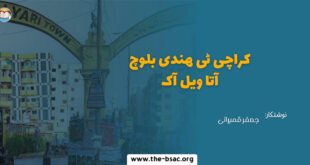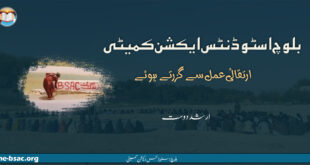علم، کتاب اور انسان: ایک فکری سفر
تحریر: وقار بلوچ (مرکزی کمیٹی ممبر ،بساک)
انسانی شعور کی ابتدائی ساعتوں میں جب انسان نے جنگل کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں کو تکتا، پانی کے بہاؤ کو سمجھتا، اور آگ کی تپش سے مانوس ہوتا، تب ہی سے وہ علم کی تلاش میں تھا۔ اس تلاش میں نہ کوئی منزل تھی نہ کوئی حد، بلکہ ایک لاامتناہی راستہ تھا جو مشاہدے، تجربے اور تجزیے سے ہوتا ہوا فہم، عقل اور آگہی کی طرف بڑھتا رہا۔ علم دراصل اس روشنی کا نام ہے جو انسان کو محض جاندار نہیں، فہم دار بناتی ہے۔ اور کتاب، وہ برتن ہے جس میں یہ روشنی محفوظ کی جاتی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔
کتاب محض اوراق کا مجموعہ نہیں، یہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں چھپے سوالات، مشاہدات اور تجربات کا تحریری اظہار ہے۔ جب کسی قوم نے کتاب کو اہمیت دی، تو وہ فکری طور پر بلند ہوئی، اور جب کتاب کو نظر انداز کیا، تو وہ فکری زوال کا شکار ہو گئی۔ تاریخ ایسے کئی لمحے رکھتی ہے جہاں کتاب جلائی گئی، علم کو قید کیا گیا، اور سوچنے والوں کو خاموش کر دیا گیا۔ مگر علم کا سفر کبھی نہیں رکا۔ وہ کبھی راکھ سے، کبھی سنگِ مزار سے، اور کبھی شکستہ دیواروں سے بھی سر نکال کر باہر آیا۔
قدیم یونان میں سقراط جیسے مفکرین نے علم کو صرف معلومات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاقی و فکری خوداحتسابی کا ذریعہ قرار دیا۔ سقراط نے سوالات کے ذریعے علم کا وہ دروازہ کھولا جو معلومات کی رٹ سے بہت دور تھا۔ اُس کا مشہور قول ہے
“An unexamined life is not worth living.”
یعنی وہ زندگی جس پر غور نہ کیا جائے، جینے کے لائق نہیں۔ سقراط نے جو طریقہ اپنایا وہ محض سوال پوچھنے کا نہیں بلکہ ذہن کو جھنجھوڑنے، سوچنے اور حقیقت تک پہنچنے کا تھا۔ اسی سوچ نے افلاطون کو متاثر کیا، جس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب “دی رپبلک” میں علم کو ریاست کی بنیاد قرار دیا۔
لیکن علم کی اس قدر پذیری کے باوجود تاریخ نے ایسے مناظر بھی دیکھے جہاں کتابوں کے انبار نذرِ آتش کیے گئے۔ چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں اسکندریہ کی عظیم کتب خانہ کو نذر آتش کر دیا گیا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں نایاب کتابیں، قدیم فلسفے، سائنسی مشاہدات، اور تاریخ کا نچوڑ راکھ ہو گیا۔ محض اس لیے کہ ایک تہذیب، جو طاقت میں تھی، وہ کسی دوسری تہذیب کے علم اور سوچ سے خائف ہو گئی۔ علم یہاں طاقتوروں کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، اور کتابوں کو جلا کر اندھیرے کو تحفظ دیا گیا۔
قرون وسطیٰ کا یورپ، خاص کر پندرہویں صدی سے قبل کا زمانہ، علم کے لیے ایک گھٹن زدہ فضا رکھتا تھا۔ چرچ نے علم پر اجارہ داری قائم کر لی تھی۔ وہ ہر اُس سوچ کو “بدعت” قرار دیتا جو رسمی عقائد سے مختلف ہو۔ گلیلیو، جو اس کائنات کی حرکات کو سمجھنے کی کوشش میں تھا، اسے چرچ نے نظر بند کر دیا، اس کا علم خطرہ بن گیا۔ اس دور میں کتاب لکھنا صرف مقدس متون تک محدود تھا، اور وہ بھی لاطینی میں، تاکہ عام انسان اسے نہ سمجھ سکے۔ یوں علم کو محدود رکھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔
علم کی اس زنجیری کیفیت سے نجات گٹن برگ کی پرنٹنگ پریس نے دی۔ پرنٹنگ پریس نے علم کو آزادی عطا کی۔ کتاب اب محض حکمرانوں یا مذہبی اداروں کا حق نہ رہی، بلکہ عوام کے ہاتھوں میں آ گئی۔ مارٹن لوتھر نے جب بائبل کا ترجمہ جرمن میں کیا تو یہ صرف مذہبی بغاوت نہ تھی بلکہ علمی آزادی کی اولین چنگاری تھی۔ یہ چنگاری بعد میں آگ بن گئی۔ یورپ میں( نشاۃ ثانیہ) (رینیسنس) یعنی نئی زندگی کے آغاز کا دور شروع ہوا۔ فن کو نئی جان ملی۔ ادب میں نئی روح آئی۔ فلسفہ نے نئی سوچ اپنائی۔ سائنس نے بھی ترقی کی راہ پکڑی۔
تاہم علم کے اس احیاء نے پرانے نظامِ اقتدار کو چیلنج کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے مفکر ولٹیر اور روسو کو جلا وطن ہونا پڑا۔ کتابوں پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ولٹیر نے کہا تھا:
“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”
اس ایک جملے نے علم اور اظہار کے رشتے کو جنم دیا۔ کتاب اب محض تعلیم کی ترسیل نہ رہی بلکہ آزادیِ فکر کا ہتھیار بنی۔
ادب اور علم کا تعلق بھی یہاں ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ روس کے فیودر دوستوفسکی نے جب جرم اور سزا میں انسانی ضمیر کی پیچیدگیوں کو بیان کیا، تو یہ علم کا وہ رخ تھا جو انسان کو انسان سے روشناس کرواتا ہے۔ علم اب لیبارٹریوں اور جامعات کا قیدی نہ رہا، بلکہ انسان کے باطن کی کھوج بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ادیب، جیسے ٹالسٹائی، کافکا، جارج آرویل، اور جیمز جوائس، سب نے کتاب کو ایسا ہتھیار بنایا جو سماج، سیاست، اور اخلاقیات پر سوالات اٹھاتا ہے۔
نوآبادیاتی دور میں یورپی طاقتوں نے علم اور کتاب کے تصور کو دو دھاری تلوار کی مانند استعمال کیا۔ ایک طرف انھوں نے اپنی نوآبادیات میں تعلیمی ادارے قائم کیے، کتابیں شائع کیں، اور ایک مخصوص فکری ڈھانچہ متعارف کرایا، تو دوسری طرف مقامی علم زبان اور تاریخ کو حقیر یا متروک قرار دیا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی لائی ہوئی تعلیم دراصل ایک خاص طبقے کی تیاری تھی جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔” میکالے “(جو اس وقت کے ہندوستان کے انگریز وزیر تعلیم اور گورنرجنرل کونسل) کی مشہور منٹ: “ہم ایک ایسی طبقه پیدا کرنا چاہتے ہیں جو رنگ اور خون میں ہندوستانی ہو لیکن ذوق، رائے ،اخلاق اور فہم میں انگریز ہو۔” یہ تعلیم دراصل علمی غلامی تھی۔
اسی نوآبادیاتی نظام نے علم کو طبقاتی بنایا کتاب کو ایک خاص بیانیے تک محدود کر دیا اور آزاد فکر کو” بغاوت” کہا۔ بیسویں صدی میں جب عالمی جنگیں ہوئیں تو کتابیں دوبارہ نشانہ بنیں۔ ہٹلر کے دور میں نازیوں نے ہزاروں کتابیں جلائیں، کیونکہ وہ نظریاتی طور پر مخالف تھیں۔ ایک ایسی کتاب بھی جس میں صرف نسلی برابری کی بات کی گئی تھی، اُس پر بھی پابندی تھی۔ گویا علم سے ڈرنے والی قوتیں ہر دور میں موجود رہی ہیں، اور کتاب ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا ہے
علم کی اہمیت اور اس کا اصل مقصد صرف ترقی یافتہ معیشت یا سائنسی ایجاد نہیں، بلکہ ایک باشعور انسان، ایک ذمہ دار شہری، اور ایک مہذب سماج کی تشکیل ہے۔ علم ہمیں نہ صرف یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیسا ہونا چاہیے۔ جب علم صرف ہنر اور معلومات تک محدود ہو جائے تو وہ محض “ابسولیٹ اسکیل ” بن کر رہ جاتا ہے۔ جب وہ انسان کی روح، فکر اور اخلاق کو چھوئے، تب وہ “حکمت” بن جاتا ہے۔
آج کا المیہ یہ ہے کہ علم کو صرف معیشت کا آلہ بنا دیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے صرف ملازمت دینے والی فیکٹریوں میں بدل چکے ہیں۔ فلسفہ، ادب، تاریخ اور دیگر انسانی علوم کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ فوری مالی فائدہ نہیں دیتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی علوم نے انسان کو سوال کرنا سکھایا، خودی کی تلاش دی، اور دنیا کو بہتر بنانے کا وژن عطا کیا۔ مشہور امریکی ماہر تعلیم جان ڈیوی کا کہنا تھا:
“Education is not preparation for life education is life itself.”
یہ قول دراصل اُس علم کی تعریف ہے جو انسان کے پورے وجود کو سنوارتا ہے، نہ کہ صرف اس کی معیشت کو۔تاریخ کے ہر دور میں علم وہ آئینہ رہا ہے جس میں انسان نے خود کو پہچانا۔ مگر جیسے جیسے انسان نے یہ آئینہ توڑنا شروع کیا، وہ خود بھی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ علم کے بغیر سماج صرف افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، ان میں کوئی اخلاقی یا فکری ربط نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم سے خالی معاشرے نفرت، تعصب، جبر اور جھوٹ پر قائم ہوتے ہیں۔
لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات علم کی ظاہری چمک نے انسان کو اندھا بھی کر دیا۔ ایٹم بم بنانے کے پیچھے بھی علم ہی تھا، مگر یہ علم فہم سے خالی، اخلاق سے عاری اور ضمیر سے کٹا ہوا تھا۔ اصل علم وہ ہے جو سوال کے ساتھ ساتھ احساس بھی پیدا کرے۔ جس میں عقل کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔
کئی جدید مفکرین جیسے نوم چومسکی اور ادوارد سعید، اس بات پر متفق ہیں کہ علم کو آزاد رکھنا، اس کی سوالیہ فطرت کو برقرار رکھنا، اور اسے صرف طاقت یا سیاست کا آلہ نہ بننے دینا، ہماری فکری بقاء کے لیے ضروری ہے۔ چومسکی کہتے ہیں:
“The purpose of education is to help students find out what is significant and worthwhile in life.”
یہ وہی علم ہے جو انسان کو اندر سے بہتر بناتا ہے، باہر سے نہیں۔
اور کتاب، اس پورے سفر کی ہمسفر ہے۔ وہ تنہا بھی سکھاتی ہے، خاموش بھی بولتی ہے، اور وقت کی دیوار پر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اسے قید کرنا ممکن نہیں، اور جلانا بھی بے سود۔ کیونکہ ایک کتاب ختم ہوتی ہے، تو دوسری جنم لیتی ہے۔ انسان کی سوچ اور جستجو کو مٹایا نہیں جا سکتا۔
علم اور کتاب کا یہ رشتہ جتنا قدیم ہے، اتنا ہی تازہ بھی۔ آج جب ہم ڈیجیٹل دنیا کے مکین بن چکے ہیں، تب بھی کتاب کی وہی حیثیت ہے۔ چاہے وہ کاغذ پر ہو یا اسکرین پر، اصل چیز اس کا مواد، اس کا اثر، اور اس کی سچائی ہے۔ ایک اچھا معاشرہ وہ ہے جو سوال کرنا سکھائے، اختلاف کو سنے، اور کتاب کو زندہ رکھے۔
علم کا ارتقاء انسان کے ارتقاء سے جڑا ہے۔ اور جب تک انسان خود کو جاننے، سمجھنے اور بہتر بنانے کی جستجو میں ہے، تب تک علم کا سفر جاری رہے گا۔ وہ کتابوں میں سانس لیتا رہے گا، وہ سوالوں میں زندہ رہے گا، اور وہ ان سوچنے والوں کے دل و دماغ میں محفوظ رہے گا جو جانتے ہیں کہ علم طاقت سے زیادہ ذمہ داری ہے۔